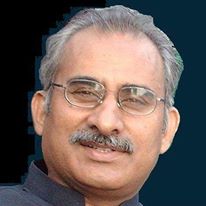
بدلتی ہوئی دنیا میں ادب کا کردار
از، محمد حمید شاہد
میں نے اس موضوع کو کورے کاغذ پر لکھا ہی تھا کہ سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی ۔ خود پر جبر کرکے بدن میں تیرتی اس سنسی کو کاٹا تو کُھلا کہ یہ موضوع سیدھے سبھاؤ کُھلنے کا ہے ہی نہیں ۔میں نے عنوان کا سوانگ بھرتے اس آدھے پونے جملے کے آگے استفہامیہ علامت لگائی اور اسے کھلا بھی رہنے دیا ؛ ہر دو صورتوں میں یہ میری چھاتی چاٹے بنا ٹلتا ہی نہیں تھا ۔ سو میں نے اپنے تئیں یہ حیلہ کیا ہے کہ مکمل تشویش اُچھالتے اس نامکمل جملے کو بھی دو حصوں میں بانٹ لیا ہے۔ ایسا کرنے سے بدلتی ہوئی دنیا کی دہشت الگ ہو گئی ہے ۔ ادب کا کوئی کردار اس دہشت کے منظر نامے میں ہے یا نہیں ؟، اس سوال کو میں نے الگ کونے میں لڑھکا دیا ہے ۔
بدلتی ہوئی دنیا کیا ہے ؟ اوراس کے بدلنے کاپیمانہ کہاں سے میسر ہوگا ؟ کسی زمانی پڑاؤ کے بیچ لکیریں ڈال کر سوچیں گے تو کچھ پلے نہ پڑے گا ،تو یوں کرتے ہیں کہ زمانے کو بدلتی ہوئی زندگی سے تعبیر دے لیتے ہیں اور زندگی کو اس لٹمس سے ، جو ایسڈ سلوشز میں ڈوبتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے اور الکلائن میں غوطہ زن ہوتا ہے تورنگ بدل کر نیلا پڑ جاتا ہے۔ رنگ بدلتی اس زندگی کو سمجھنے کے لیے میں نے پانچ دائرے لگائے ہیں ۔ یہ پانچوں دائرے اپنے اپنے مراکز پر گھومتے تو ہیں ،ایک دوسرے کو کاٹتے اندر تک گھستے اور جزوی طور پر منطبق بھی ہوتے ہیں ۔ پھر جس علاقے میں ایک دائرے کا دوسرے دائرے پر انطباق ہوتا ہے ،وہیں ان کے بیچ ایک انفساخ کو بھی دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔
سب سے پہلے دائرے کے اندر میں نے ’’فرد فرد زندگی‘‘ لکھا ہے اور اسے انسانی زندگی کی ابتدا جانا ہے ۔ جب ہر فرد اپنی ذات میں کلی طور پر آزاد تھا ۔آپ اسے انسانی تہذیب کا اولین بیج کہہ سکتے ہیں ۔دوسرے دائرے میں ’’قبائلی زندگی‘‘ لکھ لیجئے اور یہ تب کی بات ہے جب انسان نے اپنی ضرورتوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر لیا تھا ۔تن انہی انسانوں میں سے ایک ان سب پر بااختیار ہوا اور اتنا اختیار حاصل کرتا گیا کہ وہی آزاد تھا اور پورا قبیلہ اس کا غلام ۔ ان دو دائروں کے درمیانوہ انظباقی علاقہ پڑتا ہے جہاں زندگی جفت کے جوہر سے آشنا ہوئی ۔ تب عورت اور مرد ایک دوسرے پر حاوی نہیں تھے بلکہ وہ اپنے آزاد اشتراک سے زندگی کے تسلسل کے امین تھے۔
حکمرانی کا لوبھ قبیلوں کا پیٹرن بننے کے بعد انسان کے من میں آیا ، قبیلوں کے اتصال اور مخاصمت کے عمل سے معاشرتی دائرہ وجود میں آیا ۔یہ وہ تیسرا دائرہ ہے،جو دوسرے دائرے کے مشترکہ علاقے میں خاندان کی شباہت مکمل کرتا ہے اور چوتھے دائرے پر منطبق ہوتے وقت تہذیب اور روایت کی نمو اور بالیدگی کے اہم سوال سے جُڑ جاتا ہے۔
چوتھے دائرے میں تہذیبی زندگی کو جدید سائنسی زندگی کی جانب جست لگاتے دیکھا جا سکتا ہے ۔ اس جست کی غَلبَلا میں انسانیت کے قدم تہذیب اور روایت کی سرزمین سے اُکھڑے گئے ہیں اور یہ ایسی زندگی ہے جو چوتھے اور پانچویں یعنی اب تک کے آخری دائرے کے مشترکہ علاقے میں پڑتی ہے۔جسے میں نے آخری دائرہ کہا ہے اسی کو اب صارفی زندگی یا معاشی بالادستوں کی چیرہ دستیوں کا زمانہ بھی کہا جا سکتا ہے ۔ ۔۔ اور صاحب، یہی تو ہمارا بدلا ہوا زمانہ ہے۔
اس صارفیت یا کنزیومرازم والے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ اس میں چند ایسی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھوں میں سرمائے کا ارتکازہوتا چلا گیا ہے جو اسے ضرب دیے چلے جانے پر قادر ہیں پیسہ پیسے کی افزائش کرتا ہے، سو افزائش خوب ہو تی رہی ہے، مگر ظلم یہ ہوا ہے کہ اس سارے عمل میں ان کا نسلی اور مذہبی تعصب بھی پوری طرح بیدار ،متحرک اور کارفرما رہا ہے۔یہی سبب ہے کہ عالمی سطح پر بہت سے فیصلے، بہت غیر محسوس انداز میں ان ہی کی ایما پر ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں، حتی کہ واحد عالمی قوت بن جانے والے ملک کے اپنے داخلی سیاسی قضیے ہوں یا بین الاقومی تعلقات ، پیدا واری مراکز میں گھسنا ہو یا ان پر قبضہ، نئی نئی منڈیوں کی دریافت ہو یا ان کی ازسر نو تنظیم ، حربی قوت کے استعمال کے فیصلے ہوں یا سامان حرب کی فروخت اور ترسیل، دست نگر حکومتوں کی ثقافتی پالیسیاں ہوں یا سیاسی فیصلے ، ان حکومتوں میں ردو بدل ہو یا انہ س کام نکلوانے کی تدبیریں ، تہذیبی ٹھہراؤ کو بنیاد پرستی کا طعنہ دینا ہو یا معاشروں کے اپنے اندرونی تضادات کو ہوا دے کر لوگوں کو باہمی دشمن بنا کر دہشت گردی کی طرف دھکیل دینا ، روایت اور عصری زندگی کے تال میل سے قوت پانے والے تخلیق پاروں کو محض متن کی سطح پر گرانا ہو یا خالص تہذیبی تخلیقی مزاج کی بیخ کنی ، ہر کہیں بین لاقوامی سرمایہ کاروں کے تعصبات نہ جانے کیوں ، ہمیں درست یا غلط، کم یا زیادہ دخیل نظر آتے ہیں۔
ایڈورڈ سعید نے اپنے ایک مضمون میں ایک سیاسی تجزیے کا حوالہ دیتے ہوئے نشان زد کیا تھا کہ عالمی سرمایہ کاری کے اس زمانے میں سرحدوں کو کمزور کیا گیا ہے ، الگ قومی شناخت پر چوٹ لگائی گئی ہے، معاشروں اور قومی اداروں کو داخلی عدم استحکام سے دو چار کیا گیا ہے ۔ مقامی ثقافتیں تہذیبی شناخت سے کٹ کر سرمائے کی اقلیم میں داخل ہو گئی ہیں ، انفرادی میلانات کو قومی میلانات پر ترجیح دی جاتی ہے اور دُنیا بھر کے پانچ میں سے صرف ایک انسان کو سرمائے کی بڑھوتری کے آلہ کار کے طور پر چُن لیا گیا ہے جب کہ باقی چار بٹا پانچ دنیا ایسے اپاہج کی صورت ہو گئی ہے جس کا ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے اور دوسرا پیچھے ۔ صاحب ، اسی اپاہج دنیا میں میں بھی رہتا ہوں اور آپ بھی ، اور وہ بھی جو ہم میں سے ہیں مگر ادھر سے آنے والی مجہول روشن خیالی کو خلوص سے حرز جاں بنائے ہوئے ہیں یا پھر اپنے ہاں مات کھاتی روایت سے اوب کر ادھردیکھتے ہیں تواس کی چکا چوند ان پر چڑھ دوڑتی ہے۔
تو معاملہ یہ ہے کہ میرے ہاں تو بدلے ہوئے زمانے کی تصویر کچھ ایسے ہی کٹی پھٹی بنتی ہے ۔ میں نے اس تصویر کو اپنے ایک افسانے میں گوگول کے ہاں بننے والی نامکمل رہ جانے والی تصویر کا سا قرار دیا تھا جس کی شیطانی آنکھوں کو دیکھتے ہی اُبکائی آ جاتی تھی۔ اس تصویر کی شیطانی آنکھوں میں بلا کی بلا کی چمک ہے ۔ اس چوندھ میں تہذیبی زندگی کا دائرہ سمٹتا جا رہا ہے ۔ یوں اب ہم عنوان کے دوسرے حصے سے جُڑ جاتے ہیں کہ اس سمٹتے دائرے میں کیا ادب اپنی تخلیقی سانسوں کوبحال رکھ پائے گا یا یہ بھی بدلتے ہوئے زمانے کے سب سے کارگر حربے یعنی سطحیت ، اشتہاریت اور صارفیت کا لقمہ ہو جائے گا۔
یہیں سارتر کی ایک بات یاد آتی ہے ۔اس نے لکھا تھا:
’’امریکہ میں آپ سڑک پر اکیلے نہیں رہ سکتے ، دیواریں تک آپ سے باتیں کرتی ہیں ۔ دائیں بائیں آپ کو تختوں پر لگے اشتہار ، جگ مگ کرتے سائن بورڈاور دکانوں کی بڑی بڑی آراستہ کھڑکیاں نظر آتی ہیں جن میں ایک تو بڑی سی تصویر ہوتی ہے اور کچھ اعداد و شمار ۔ ان تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہ ایک پریشان حال عورت ایک امریکی سپاہی کو اپنے ہونٹ پیش کر رہی ہے ، یا ایک ہوائی جہاز کسی شہرپر بمباری کر رہا ہے اور تصوہر کے نیچے لکھا ہوا ہے ’’بم نہیں ،انجیل‘‘
اب اگر ایک طرف منہ پھاڑ کر اور سنجیدگی سے سوچے بغیر،بہت کچھ بدل دینے کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف ہمارے پچکے ہوئے تہذیبی وجود سے اندر کے سارے تضادات باہر ابل پڑے ہیں ۔ تضادات نہ کہیں گند کہیں ۔ جب تک ہمیں خارج سے ٹھوکر نہیں لگی تھی، ہم اندر کا سارا گند اپنے اندر ہی سنبھالے ہوئے تھے، جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ تضادات تھے مگر یہ اس طرح کھل کر سامنے نہ آئے تھے ۔ فرقوں اور گروہوں میں تب بھی بٹے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں حیا تھی ، ایک دوسرے کا پاس تھا ، تب ایک انسان کا قتل ،پوری انسانیت کا قتل ہوتا تھا مگر جہاد کے نام پر ہم ایسی جنگ کا حصہ بنے ہیں کہ اب ہر کہیں اسی نام نہاد جہاد کو برپا کرنے پر تلے بیٹھے ہیں اور اندر سے اتنے سفاک ہو گئے ہیں کہ دوسرے فرد کی جگہ پر کھڑے ہو کر سوچناتو درکار اس کا وجود تلف کرنے کے درپے رہتے ہیں ۔بش نے ۲۰ ستمبر ۲۰۰۱ کووار انگیسٹ ٹیرر یعنی ’’دہشت گردی کے خلاف جنگ ‘‘ کی جو اصطلاح اُچھالی تھی اس میں اب تک بہت کچھ اچھا لا جا چکا ہے۔
ضرب عضب کے اس زمانے کے آنے تک مرنے والے بھی ہم ، مارنے والے بھی ہم ، اس سارے خونی تماشے میں ڈالروں اور اسلحے کی ریل پیل رہی ۔ سو ہم شقی القلب ہو گئے ۔ شاید آدمی اندر سے ہوتا ہی ایسا ہے ۔ اوپر حالات ایک ملمع چڑھا دیتے ہیں ، بس وہ ویسا ظاہر کرتا ہے جیسے اس کے حالات ہوتے ہیں ۔ بھوک سے ہماری بکھیاں پہلے ہی اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، اس بھوک نے ہمیں لڑایا۔ کہنے کو ہم اہل کتاب تھے ، مگر ہم جس مولوی سے علم سیکھتے تھے ، وہ خود مذہب کی اصل روح سے نا آشنا اور علم کا دشمن نکلا۔ ،اس نے اپنی دکان چمکانے کے لیے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا ۔ پھر یہ مولوی بھی ہر برانڈ کا تھا ، فیشن شو کے ریمپ پر قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والا، ، ایک شادی اور کئی نامحرم عورتوں سے نکاح جائز قرار دینے والا، حتی کہ کسی معصوم کو مرغی کی طرح ٹانگوں کے نیچے دبا کر گردن تن سے جدا کر دینے والا۔ اقبال کا کہا یاد آتا ہے:
اُٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غم ناک
نہ زندگی،نہ محبت ، نہ معرفت ،نہ نگاہ!
مذہب کے نام پر قائم سیاسی جماعتیں ڈرامہ ثابت ہوئیں ۔ اچھا وہ روشن خیال اور لبرلز، جو ہمارے مزاجوں میں اعتدال انڈیل سکتے تھے ، ایک مذہب سے وابستہ ہونے کو گالی بنا دینا چاہتے ہیں ۔ دوسری طرف جمہوریت کا دم بھرنے والی سیاسی جماعتیں چند جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے گھر کی لونڈیاں نکلیں اور انہیں کے سرمائے کو ضرب دیئے جاتی تھیں۔اسٹیبلشمنٹ، اپنے کام سے کام رکھنا کب کی بھول چکی ، سیاست کا چسکا اسے لگ چکا ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے تضادات اور بھی واضح ہوتے چلے گئے۔
اچھا صرف ہمارے تضادات سامنے نہیں آئے اِدھر اُدھر ایک سا چلن ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر فہمیدہ ریاض کا ایک نوٹ پڑھا تھا جو انہوں نے اپنے شہر میں کہیں ہونے والی تقریروں کے سبب ٹریفک میں پھنس جانے پر لکھا تھا۔ر پچیس منٹ کا راستہ دو گھنٹے میں طے ہوا ،گھر پہنچ کر خبریں ایسی پڑھنے کو ملیں کہ ڈپریشن ان پر چڑھ دوڑا۔انڈین ایکسپریس کی خبر کے مطابق، اُدھر ایک جلسے میں کسی نے کہا تھا: ’’مسلمانوں کو ایک بار پھر مزا چکھائیں گے‘‘ اور امریکہ سے آنے والی خبرکے مطابق ، ٹرمپ نے اپنے جلسے سے سیاہ فام طالب علموں کو نکلوا دیا تھا۔ڈیپریش کی اسی کیفیت میں فہمیدہ نے لکھا: ’’ یہ کیا ہو گیا ہے دنیا کو ؟، ایک دوزخ میں تبدیل ہو رہی ہے دنیا ۔ جینے کو دل نہیں چاہتا اورحیرت ہے مرنے کو بھی۔۔۔ اتنی بری جگہ مرا جائے کیا؟‘‘
تو یوں ہے کہ ہم لکھنے والے اسی دنیا میں ہیں جس میں مرنا بھی ہتک ہو گیا ہے ۔ لگ بھگ اتنی ہی ہتک جتنی ، منٹو نے ’’ سوگندھی‘‘ کے معاملے میں دکھا دی تھی ۔ جہاں ہم ہیں وہاں تو موت اور زندگی دونوں کوکچھ زیادہ ہی عبرت کی علامت بنا دیا گیا ہے ۔ گزشتہ دنوں، لوک ورثہ میں مادری زبانوں کا میلہ تھا ۔اس میلے میں ہر کوئی اپنی ماں کی زبان کے مرنے کی خبر دے رہا تھا۔ جی ہاں وہ زبان جس میں اس نے بچپن میں لوریاں سنی تھیں اور اپنے لہو کی حدت کو بڑھتے پایا تھا ، وہ زبان بے بسی سے مررہی تھی ۔ کوئی زبان مرتی ہے تو اس کا سارا تہذیبی اثاثہ بھی مر جاتا ہے ، مگر اس بدلی ہوئی صورت حال میں تہذیبی اثاثہ ایک بوجھ ہو گئی ہے اور زبان محض سرمایہ کار کا ہتھیار۔ ہمیں جتلایا جا رہا ہے کہ یہ اسی حد تک زندہ رہ سکتی ہے جس حد تک وہ سرمایہ کار کے پیغام کو صارف تک پہنچا سکتی ہے اور بس۔ہماری حکومتیں اس دباؤ میں ایک روک فراہم کر سکتی تھیں ، انہدام کی رفتار میں رخنے ڈال سکتی تھیں اور مواقع فراہم کر سکتی تھیں کہ اردو زبان اس تہذیبی ورثے کو جذب کرلے اور ان فاصلوں کو پاٹ لے جو یہاں کی قومی زبانوں کے درمیان ہیں مگر ان حکومتوں کو تو ہر دم اپنے گرنے کا خدشہ لگا رہتا ہے۔
یہ ہے وہ صورت حال جس میں ادب کو اور زبان کو اپنا کام کرنا ہے ۔ معاملہ یہ ہے کہ سرکار کے پاس ادبی اداروں کو دینے کے فنڈز نہیں، یہاں نہ توکوئی لسانی پالیسی ہے نہ ثقافت کے فروغ کی منصوبہ بندی ، سب کچھ جدید تر انفارمیشن کے نام پر آنے والے سیلاب میں بہے چلا جارہا ہے ۔ ہونٹوں ، بموں اور اشتہارات کی نفسیات نے ہماری لسانی،ادبی اور تخلیقی روایات کو اتنے چرکے لگائے ہیں،کہ ادبی سرگرمی کو سنجیدہ اور تہذیبی عمل سمجھنے کی بجائے محض ایک ثقافتی غلغلہ سمجھا جانے لگا ہے ،یا پھر ایسی سرگرمی جس کے مارکیٹ میں دام بھی لگ سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے صارفیت کے اس زمانے میں کاروباری ساکھ بنائی جا سکتی ہے۔
ایسے میں، میں خلوص نیت سے سمجھتا ہوں کہ ادب کا اگر کوئی کردار ہے تو وہ اتنا کہ دباؤ میں آکر گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے اس زمانے کی ہوا کے ساتھ رُخ بدلے نہیں بلکہ منہ زور تھپیڑوں میں اپنی بچی کھچی تہذیبی شناخت سے جڑار ہے ، اپنی خامیوں اور کجیوں کو جھٹک کر، اور اسی تہذیبی مقام سے وابستہ رہ کر رواں منظر نامے کو اپنی روح سے مکالمے کے مواقع فراہم کرے ۔ لکھنے والے کو، اپنے ہاں دہشت زدگی، مرعوبیت اوراُتاولے پن کو پرے دھکیل کر تخلیقی عمل کو کام کرنے دینا ہے ۔ یہی طرز عمل ہمیں اور ہمارے ادب، حتی کہ تمام انسانی تہذیبی مظاہرکودہشت ، تعصب اور صارفیت کے منہ زور تھپیڑوں سے بچاسکتا ہے ۔




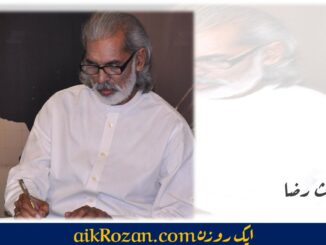
مطلب یہ کہ ادیب اپنا نظریہ رکھے، اسے لکھے اور تشہیر کرے۔ خریدے گا کونَ؟؟
بہت عمدہ لکھا ہے محترم حمید شاہد صاحب لیکن ! وہ کان اور دل کہاں سے لائیں گے جو سن اور سمجھ سکیں۔ قومیں اپنے فکری اور ثقافتی اثاثہ جات کے بل پر عالمی یورشوں کا مقابلہ کیا کرتی ہیں، جبکہ ہم فکری و ثقافتی طور پرانتشار کا شکار ہیں۔
سب سے بڑھ کر ظلم یہ کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ آج آپ کے ساتھ کون کون ہے جو یہ سوچے سمجھے اور پھر سمجھانے کا روگ پالے۔ بہرحال دیا جلانے پر مبارکباد قبول کیجے