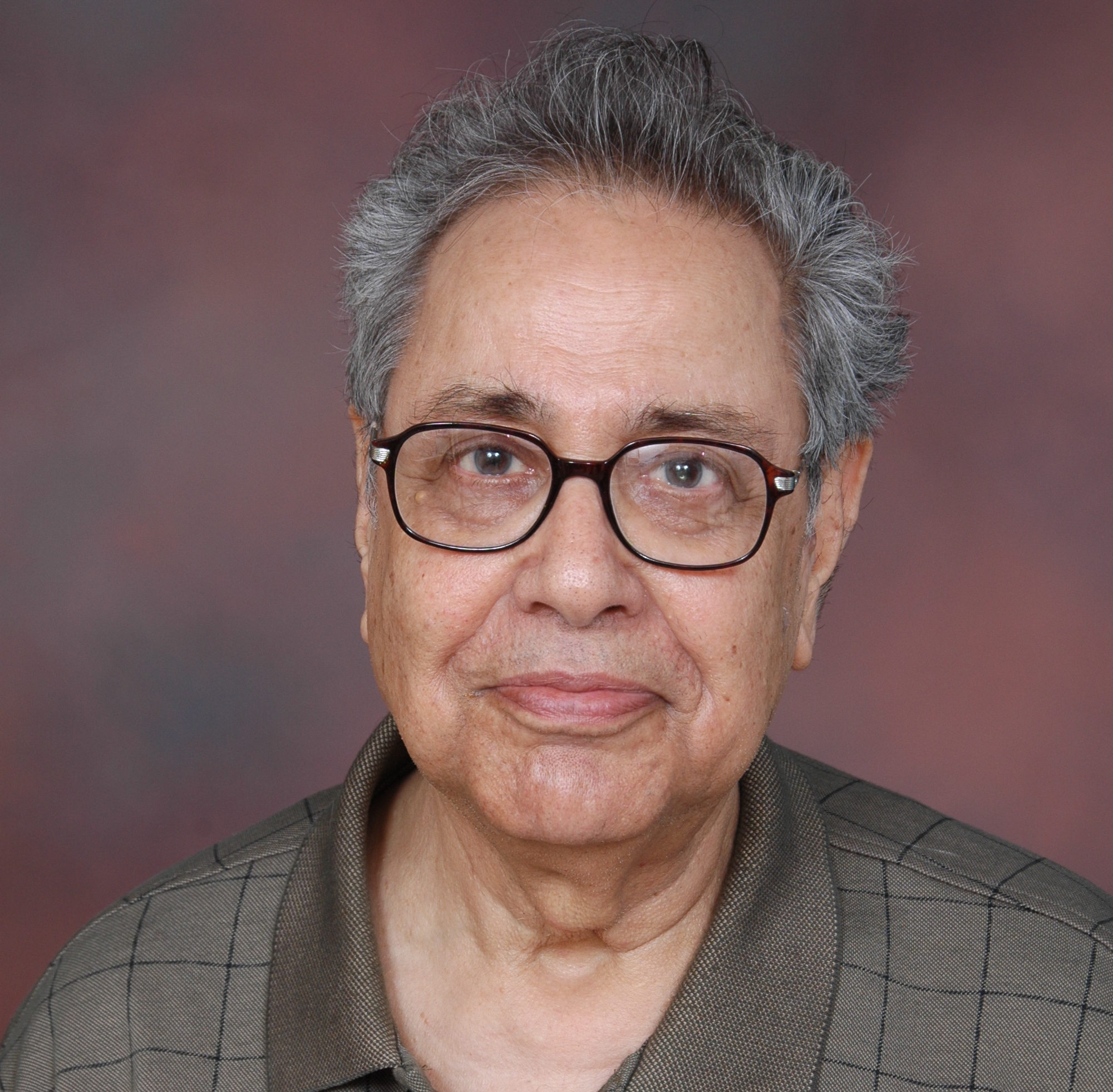
(ڈاکٹر ستیہ پال آنند)
عارفہ شہزاد کلیتاً اکیسویں صدی کی شاعرہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اکیسویں صدی سے ہی لکھنا شروع کیا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے نسائی حسیت کی شاعری کو ایک نیا رخ دینے میں کچھ دیگر شاعرات کے ساتھ اپنا شعری تشخص قائم کیا۔ کچھ رجحانات  جو بیسویں صدی کی آخری تین دہائیوں میں رواج پانے، نقطۂ عروج تک پہنچنے کے بعد دم توڑتے نظر آتے تھے، ان میں خصوصی طور پر نسائی حسیت کی شاعری تھی جو اپنے جوبن کے دنوں میں چیخ و پکار کی گھن گرج تک پہنچنے کے بعد کچھ دھیمی ہوئی تو یہ محسوس کیا گیا کہ اس تحریک کو سماجی علوم کی روشنی میں ایک نظریے کی ضرورت ہے، جو ’’پُرش پردھان‘ ‘سماج میں عورت کے صحیح مقام کی نشاندہی کرے۔ نعرہ بازی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ۔ خصوصی طور پر مذہب کے حوالے سے عورت کے مقام کا تعین اگر دیگر حوالوں کے ساتھ بر سر پیکار ہے تو وہ ہر جگہ کسی نئی تجویز کو ریاستی سطح پر بروئے کار لانے میں حارج ہو گا۔ یہ بھی محسوس کیا گیا کہ اس احتجاج کے شور و غل میں نظمیہ شاعری سپاٹ ہوتی جا رہی ہے۔ نعرہ بازی نے نفس مضمون کو تو برقرار رکھا ہے لیکن دیگر محاکات جو شاعری کا حسن تھے ، استعارہ، تمثال، امیجری کو ایک ہاتھ کی دوری پر رکھا ہے۔ عارفہ شہزاد کی نظموں میں اس عندیہ کا
جو بیسویں صدی کی آخری تین دہائیوں میں رواج پانے، نقطۂ عروج تک پہنچنے کے بعد دم توڑتے نظر آتے تھے، ان میں خصوصی طور پر نسائی حسیت کی شاعری تھی جو اپنے جوبن کے دنوں میں چیخ و پکار کی گھن گرج تک پہنچنے کے بعد کچھ دھیمی ہوئی تو یہ محسوس کیا گیا کہ اس تحریک کو سماجی علوم کی روشنی میں ایک نظریے کی ضرورت ہے، جو ’’پُرش پردھان‘ ‘سماج میں عورت کے صحیح مقام کی نشاندہی کرے۔ نعرہ بازی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ۔ خصوصی طور پر مذہب کے حوالے سے عورت کے مقام کا تعین اگر دیگر حوالوں کے ساتھ بر سر پیکار ہے تو وہ ہر جگہ کسی نئی تجویز کو ریاستی سطح پر بروئے کار لانے میں حارج ہو گا۔ یہ بھی محسوس کیا گیا کہ اس احتجاج کے شور و غل میں نظمیہ شاعری سپاٹ ہوتی جا رہی ہے۔ نعرہ بازی نے نفس مضمون کو تو برقرار رکھا ہے لیکن دیگر محاکات جو شاعری کا حسن تھے ، استعارہ، تمثال، امیجری کو ایک ہاتھ کی دوری پر رکھا ہے۔ عارفہ شہزاد کی نظموں میں اس عندیہ کا  سراغ ملتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نسائی حسیت کی شاعری کو منبر سے بولنے والی کی تقریر کی طرح ہونا چاہیے۔ میلان اور مطلب کو شعریت سے مملو سطروں میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو اس کتاب کے عنوان سے ہی عیاں ہے۔
سراغ ملتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نسائی حسیت کی شاعری کو منبر سے بولنے والی کی تقریر کی طرح ہونا چاہیے۔ میلان اور مطلب کو شعریت سے مملو سطروں میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو اس کتاب کے عنوان سے ہی عیاں ہے۔
عارفہ کی وہ نظمیں بھی جن میں یہ جذبہ ابھر کرآتا ہے، مزاحمت، اجتہاد، یا عورت اور مرد کے مابین تنازعہ للبقا کی کیفیت کی حامل نہیں ہیں۔ بہت سی نظمیں تو ایسی ہیں جو دو پریمیوں کی خاموش کفتگو، یعنی من و تو کے فارمیٹ میں ہوتے ہوئے بھی ، اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہیں اور جن کی نرم و نازک ا دائیگی سے اٹھتی ہوئی خوشبوئیں اوس کے قطروں کی طرح دل پر ٹھنڈک اور مٹھاس چھوڑ جاتی ہیں۔
یہ کیا روشنی ہے
جو آنکھوں میں کرنوں کا میلہ لگا دے
زمیں آسماں جگمگا دے!
کہاں سے ہے جاگا؟
یہ خُوشبو کا منہ زور جھونکا
کہ دل کے مقفّل دریچے، کھُلے ایک پل میں
یہ کیسا اثر ہے!
تمھیں کچھ خبر ہے؟
یہ نظم آخری سطر تک ’’من و تو‘‘ کے فارمیٹ کو معرضِ التوا میں رکھتی ہے۔ روشنی، کرنیں، آنکھیں، میلہ، زمین و آسمان، خوشبو، جھونکا، مقفل دریچوں کا ہوا کے زور سے کھلنا … جانے پہچانے مناظر ہیں اور قاری کو ایک جاگتے سحر میں گرفتار رکھتے ہیں…اور پھر دو سطریں دل کے اکتارے کے تار پر زور کی جھنجھناہٹ سے اختتامیہ کا دیر تک بجتے رہنے کا تاثر چھوڑ جاتی ہیں۔
یہ کیسا اثر ہے…. تمہیں کچھ خبر ہے؟
ایک اور نظم میں بھی یہی کیفیت ایک دوسرے طریق کار سے دہرائی گئی ہے۔ اس کی شروعات تو یہ سطریں تصویر میں ڈھالتی ہیں…
ہتھیلی میں مری سورج اتر آیا
بنی ہیں انگلیاں کرنیں
میرا دل ششدر وحیراں تکے
ہر پور کی صورت
مرے ہونٹوں کی ساری مسکراہٹ
کس کے ہونٹوں پر کھلی ہے
زندگی ایسے ملی ہے
سارے منظر گنگناتے ہیں
ا بھی تک سر سراہٹ سی کوئی دل سے لپٹتی ہے
میری باہوں میں ہے کس کے
رُوپہلے پیار کا کنگن
ایسے لگتا ہے جیسے جیسے وہ کہانی جو آنکھوں میں کرنوں کا میلہ سجاتی تھی، جس میں خوشبو کے جھونکے جب دل کے مقفل دریچوں پر دستک دیتے تھے تو دریچے خوش آمدید کہتے ہوئے جھٹ سے کھل جاتے تھے، جس میں ہتھیلی پر جیسے سورج اتر آتا تھا اور کرنوں میں تبدیل ہوئی انگلیوں کی پوریں کی طرح رنگا رنگ مسکراہٹیں ہونٹوں پر جگمگا اٹھتی تھیں …وہ کہانی کہیں بیچ میں ہی قتل ہو گئی یا قتل کر دی گئی۔
مجھے اب یاد کچھ آتا نہیں ہے
کہیں رکھی تھیں شاید طاقچے پر
اُنھیں الماریوں میں ڈھونڈتی ہوں
یہ کس دزدِ دلاور نے چرائیں
ورق پر ہیں نہ دل میں ہی نہاں ہیں
تمھارے ہجر کی نظمیں کہاں ہیں ؟
وصل … اور اس کے بعد ہجر …یہ تو اردو شاعری کا آزمودہ طریقِ کار ہے۔ ایک ایسا نسخہ ہے جس سے کوئی بھی شاعر آج تک نہیں بچ پایا، لیکن کچھ ایک شعرا کے یہاں ہی اس کی وہ جہت ملتی ہے، جو عارفہ شہزاد کی نظموں میں کسی بلند بانگ اعلامیے کے بغیر در آ تی ہے، اور آج کی بیشتر شاعرات کو مرد شعرا سے الگ کرتی ہے۔ اس جہت کا چہرہ مہرہ پرکھنے کی ضرورت ہے۔
مجھے خوشی ہے کہ عارفہ شہزاد کی نظمیں الجبرے کے سوالوں یا معمہ نویسی کی طرح نہ ہو کر سمجھی جا سکنے والی نظمیں ہیں۔ ان سے ایسے ہی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے ، جیسے بانسری پر بجتی ہوئی دھن سے، یا کسی گڈریے کے دور سے آتے ہوئے ماہیا کے بولوں سے ۔ یہی خوبی ان کے مخصوص انداز کو منفرد بناتی ہے ۔ اپنی ذات تو ہر شاعر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے بعد کائنات تک پہنچنے کا سفر ہے لیکن اس سفر کے دوران میں بھی ذات کا تشخص گم نہیں ہونے پاتا۔ اس طرح کی نظمیں جو عارفہ کی کتاب میں ملتی ہیں، ہمیں فوراً ہی اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔
پریت کی چوڑی بانہہ میں ڈالی
آنکھ میں یاد کا کا جل
ٹانک کے تارے آرزوؤں کے
خواب کا اوڑھا آنچل
نین نشیلے، خواب سجیلے
کون مچائے ہلچل؟
روپ عجب ہے، رنگ غضب ہے
کون؟
یہ میں ہوں ۔۔۔ ؟
پاگل!!!
’’یہ میں ہوں ….؟، پاگل!!!‘‘ خود کلامی ہے بھی اور نہیں بھی،کہ خود کلامی میں واحد متکلم کا ایک تشخص ہی بولتا ہے، جبکہ یہاں دو تشخص بہم گفتگو میں محو ہیں۔
شاعرہ نے دقیق اور جھلی دار باریک، دونوں اقسام کی علامتوں کو اپنانے سے گریز کیا ہے۔ جہاں ضروری سمجھا ہے وہاں استعارہ سازی سے بخوبی کام لیا ہے ، جہاں براہ راست بیانیہ ، بصری مناظر کی مدد سے ، خیال اور جذبے کی ترسیل میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہاں علامت کو غیر ضروری سمجھا ہے۔ “خود”، یا “میں” یا “ذات” سے کائنات تک کا سفر، مجھے محسوس ہوتا ہے، کہ شاعرہ نے شاید ایک ہی جست میں طے کر لیا۔ یعنی روپ، رنگ، نشیلے نین، سجیلے خوابوں، پریت کی چوڑیوں اور یاد کے کاجل والی یہ شاعرہ ، اپنے اندر کی سچائی سے ….چشم زدن میں جب باہرجھانک کر دیکھتی ہے ، تو اسے یہ مناظر دکھائی دیتے ہیں۔
آگ، جانے کن آتش دانوں سے، چرا کر لائی گئی تھی
ہم اِس پر پھٹکڑی ڈال کر جلاتے رہے
مگر دشمنوں کی شکل واضح نہ ہو سکی
جلی ہوئی پھٹکڑی، چوراہے میں پھینکنے پر بھی
خوفزدہ بھاری بوٹ
اِسے قدموں تلے روندنے سے بازنہ رہ سکے
ٹوٹی چپل، چوراہے میں پھینکے کا ٹوٹکا بھی کیسے آزمائیں؟
ہم تو اَزلوں سے ننگے پاؤں چل رہے ہیں
درختوں سے آرزوؤں کی دھجیاں باندھتے باندھتے
ہمارا وجود دھجیوں میں ڈھل گیا ہے
چوکھٹ پر بکروں کا صدقہ دیتے دیتے
ہم ہار گئے
ری اماں!
اِس لہو میں
تازہ لہو کی دھاریں کہاں سے آ جاتی ہیں؟
سارا گھر مذبح خانہ بن گیا ہے!
پنجاب میں ہجر سے مملو سب لوک گیتوں میں ’’مائے، نی مائے!‘‘ کے ورلاپ سے برہن بیٹی اپنا دکھڑا پنی امّی کو سناتی ہے تو یہ کچھ عجیب نہیں ہے کہ اس نظم میں بھی شاعرہ جیسے چیختی ہوئی کہتی ہے۔ ’’ری ماں!”
اب ایک اور نظم دیکھیں۔
زنبیل خالی ہو چکی ہے
تمھارے سامنے شعبدوں کا ڈھیر لگا ہے
ایک ایک کو الٹ پلٹ کر کیا دیکھتے ہو؟
برانڈ نیو ہیں
آج ہی مارکیٹ میں آئے ہیں!
اِن سے جی نہ بہلے تو
چوک میں پھُلجھڑیوں کا انبار لگا ہے
جھولی بھر لو
کل ہم سب
اِظہار یک جہتی کے طور پر
اکٹھے ہو کر
اِنھیں آگ دکھائیں گے
آسمان تک روشنی نہ پہنچی تو…
شُرلیوں پٹاخوں کا بھی انتظام ہے
سماعتوں کی خیر ہے
بر صغیر کی عورت اس لحاظ سے بجوگ اور محرومی کا شکار ہے کہ اسے سماج میں دوسرے درجے کا فرد گردانا گیا ہے۔ وہ خائب و خاسر ہے، پہلے اپنے خاندان میں اور پھر سماج میں محرومہ اور محروسہ ہے۔ ایک ایسی اراضی کی طرح ہے جس کے مالک کے طور پر باپ، بھائی اور شوہر اصحات الفوض ہوتے ہیں، جاگیر دار ہوتے ہیں ۔ جاگیر ’علی الاولاد و احفاد (ذکور و اناث) میں اس کا حصہ صرف لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صدیوں تک اگر وہ اس محرومی کے احساس سے غافل رہی تو اس کی دست کشی سے کسی کو تنازعہ نہیں تھا، لیکن اب اکیسویں صدی میں اگر وہ اپنا حق جتانا بھی چاہتی ہے تو بھی اسے تمادی اور محرومی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ محرومی اس احساس کمتری کا زائدہ ہے، جس سے بر صغیر کی عام عورت اس وقت دو چار ہے۔ ’’عام عورت‘‘ کو تو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ وہ ’محروم‘ ہے۔ ایک داخلی احساس کے طور یقیناًوہ اس سے زندگی کے ہر گام پر واقف ہوتی ہے (یا واقف کروائی جاتی ہے) لیکن بیاہ کے بندھن کی کسی سہاگ پوٹلی میں بندھی ہوئی یہ محرومی نسل در نسل ایسے چلتی آ رہی ہے، جیسے پرکھوں کی میراث ہو۔
عارفہ کھیت ، اس کی سیرابی، فصل بونے اور اگنے کے استعارے کو براہ راست اس حالت پر منطبق کرتی ہیں۔
مجھے یہ خبر ہے
کہ سوکھی زمینوں کی جانب پلٹنا بھی
بس میں نہیں ہے !
یہ سیراب کھیتوں کی مٹی میں ملنے کی
اور جذب ہونے کی خواہش
کہیں پیش و پس میں نہیں ہے
مگر اتنا پانی ہے، تہ میں
کہ مٹی سے مل کر
میں گارے میں ڈھلنے لگی ہوں
اسی کیچ کا حصہ بننے لگی ہوں!
میرے خیال میں اگر ہم ایلیٹ کا یہ فرمان عارفہ شہزاد کے اسلوب پر منطبق کریں تو درست رہے گا۔ ایلیٹ کہتا ہے ’’ہر لفظ اپنی پرچھائیں سمیٹتا ہے ، اور اس کے پنجے دوسرے الفاظ کی پرچھائیں سمیٹنے کے لپکتے ہیں۔‘‘ شاعرہ کا اسلوب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا قلم سلیس اور سادہ صناعی پر انحصار رکھتا ہے ۔ اس اسلوب میں تازگی ہے۔ زبان کی سلاست، تلازمات، استعارات اور تشبیہات کا استعمال اسے سادگی کا وہ ہنر دیتا ہے جو عموماً شاعرات کا خاصہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ عارفہ شہزاد مستقبل قریب میں ہی پاکستان کی شاعرات کی صف اوّل میں ایک نمایاں مقام حاصل کریں گی۔

