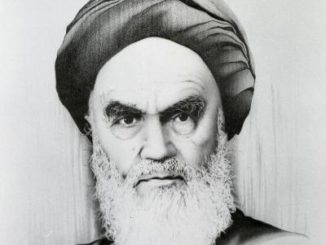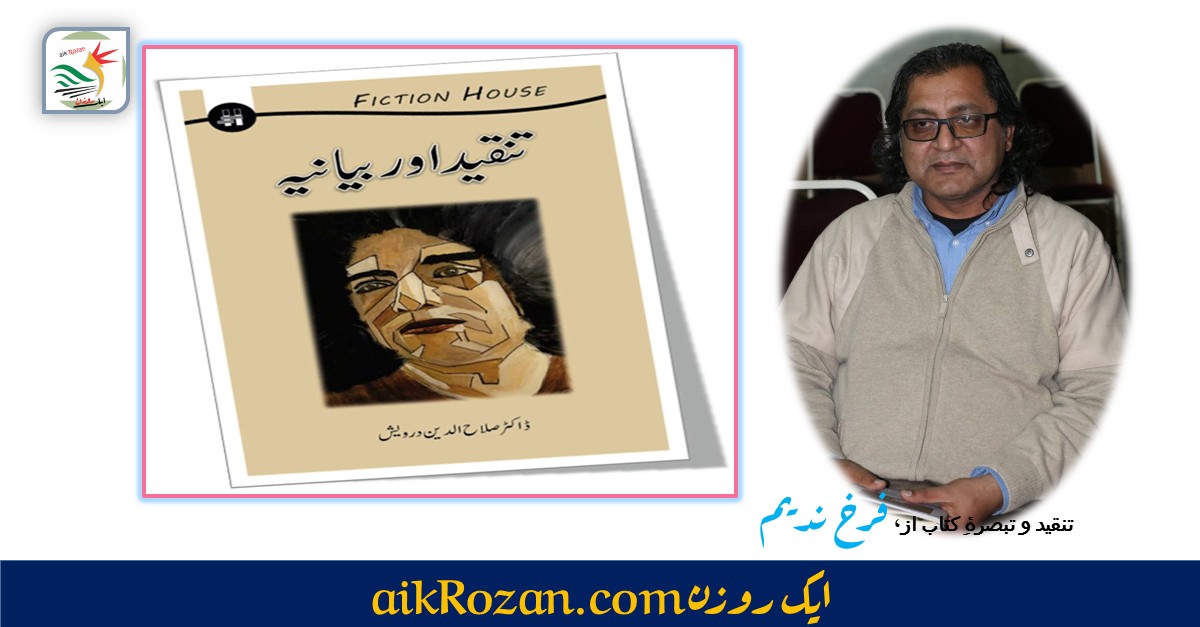
درویش کی تنقید اور بیانیہ
از، فرخ ندیم
’’تخلیقی وفور، جوش، جذبہ، خیال آرائی، تخلیقی کرب، جمال دوستی، کِشف، وجدان کا لمحہ اور آدرشی جیسی اصطلاحات خود اردو تنقید میں اس قدر بار پا چکی ہیں کہ جیسے ایک تخلیق کار کے لیے یہ اصطلاحات نہیں ہیں بَل کہ کوئی آسمانی بند و بست ہے کہ جس میں دخل دینا گویا تخلیق کو فنا کے گھاٹ اتار دینا ہے۔‘‘
بادی النظر میں یہ فکری عبارت صلاح الدین درویش کی تنقیدی شناخت ایک غیر مقلد مکتب فکر سے کرتی ہے لیکن اس عبارت کو ثنوی نظام کی رُو سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق میں تنقیدی روایت کا فکری نظام پاپولر کلچر کا ترجمان رہا ہے جس کی تہوں میں ثقافتی سیاست اور توسیع پسندی نظریاتی نسمیت کا شکار رہی ہیں۔ افقی اور آفاقی بیانیوں کی ٹھوس ثقافت میں کچھ مختلف سوچنے کی کوشش ایک استدلالی رویہ ہے لیکن مقبول ثقافتی روایت میں اسے ’آوازِ غیر‘ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یوں نظریاتی خواہشوں کے متون میں وہی کچھ معتبر ٹھہرایا جاتا ہے جو نظریاتی سماعتوں اور بصارتوں کو خِیرہ کرنے کی میکانکی اہلیت رکھتا ہو۔ صلاح الدین درویش کی تنقید اس ثنوی نظام میں دوسری طرف ہے جو روایتی تنقید کے بیانیوں اور مہا بیانیوں کے بوجھ سے آزادی کی ایک بھرپور کوشش ہے۔
چار حصوں اور کل پچیس مضامین پر مشتمل یہ کتاب اس ذہن کے لیے با لکل بے کار ہے جسے خود مرکزیت کا نشہ ہے۔ جو ہر اینٹی تھیسز کو حاشیوں پر رکھنے کا/کی عادی ہے۔ جسے شعوری ارتقا سے کوئی دل چسپی نہیں، جسے صرف جملوں کی چاشنی سے رغبت ہے، جسے لفظ اور تسلط میں کسی غیبی تعلق سے سرو کار ہے اور جسے تہذیبی مراکز کی امریہ تراکیب کا دُھت نشہ ہے، جسے فعلِ حال اور مستقبل سے متعلق معقول تراکیبِ نحوی سے دل چسپی نہیں کہ، جو غیر مکالماتی ادبی محفلوں میں وجودیت پسند لفاظی سے کیتھارسز کرتا ہو۔ یہ کتاب ایسے افراد کے لیے بھی مُضرِ صحت ہے جن کی دانش ترقی معکوس کے ان گنت دائروں سے اَٹی رہتی ہے خاص طور پر ان کے لیے جو وہی پڑھنا چاہتے ہیں جو وہ پڑھنا چاہتے تھے۔ ایسی لگی بندی سیاسی بصیرت سے اس کتاب کا دور سے بھی واسطہ نہیں۔ البتہ وہ لوگ ضرور پڑھیں جنہیں غیر مشروط ثقافتی قنوطیت سے آزادی زیادہ عزیز ہے۔
ڈاکٹر صلاح الدین درویش سمجھتا ہے کہ وہ عصری سماجی ماحول میں کسی اساطیری دور میں زندہ نہیں۔ ویسے بھی، بقول درویش، سائنسی دور میں رہ کر مہا بیانیوں میں فرار کی خواہش انسانی فکر کی تنزلی کی علامت ہے۔ یوں بھی نہیں کہ درویش کی ترقی پسند فکر کی بنیاد ردِ مذہب ہے۔ یوں ہے کہ وہ علوم و فنون اور زندگی کے عام دھاروں میں کسی بھی نظریاتی تسلط اور غلبہ پرستی کا قائل نہیں۔ اس کی یہ کتاب ادب اور سماج میں فکری مغالطوں کا تنقید ی جائزہ بھی پیش کرتی ہے۔
پسِ ساختیاتی مفکرین کی طرح درویش کی فکر انسانی تشکیل میں نفسیاتی محرکات کا ثقافتی جائزہ لینے میں دل چسپی رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر، منفیت کی نفسیات، اس کی فکر کی رُو سے ایک ثقافتی عمل ہے جسے کسی سماج کے اندر ہی مہمیز ملتی ہے۔ یعنی مُروّج معنوں اور پاپولر کلامیوں میں کسی کردار میں منفیت کو غیر منطقی حد تک فطری اور غیر تحریکی سمجھا جاتا ہے، نفسیاتی اعتبار سے ایسا ممکن نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو دنیا میں کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کوئی بھی شخص ہر قسم کے دعوؤں کا ڈھول بجا سکتا تھا۔ دعوٰی جواز اور دلیل سے مشروط ہوتا ہے۔
’’تنقید ایک خود مکتفی علم ہے‘‘ سے لے کر ’’اختر رضا سلیمی: جاگے ہیں خواب میں‘‘ تک ڈاکٹر درویش کے تمام مضامین مختلف کتابوں کے عنوانات محسوس ہوتے ہیں۔ ادب، سماج اور ثقافت کی تثلیث سے متشکل یہ مضامین فلسفیانہ بھی ہیں اورصحافتی بھی۔ عصری تخلیقی اور تنقیدی شعور انسان کے مادی ماحول کے شعور سے مشروط ہے، مادی ماحول کے تغیرات سے ہی سیاسی اور ثقافتی تبدیلیاں ممکنائی جاتی ہیں۔ درویش کی تنقیدی انفرادیت اسی سیاسی ثقافتی اور سماجی شعور سے تشکیل پاتی ہے۔ یہ شعور درویش کو مکانی تالے نہیں لگانے دیتا۔ وہ، ہر وقت اور ہر جگہ مکالمے کا در کھلا رکھتا ہے۔ اس کے تمام مضامین پڑھتے یہ احساس موجزن رہتا ہے کہ عالم گیریت کے عالم میں تنقید کا خانقاہی اور معذرت خواہانہ بیانیہ بڑی سطح پر نا کام ہو جاتا ہے۔ بند کواڑوں میں تیار شدہ تفہیم و تعبیر عالم گیر سیاسی فضا سے اتنی خوف زدہ ہے کہ چھوٹی موٹی گلیوں میں گھوم پھر کر پھر اپنے خالقوں سے جا ملتی ہے۔ درویش کی تنقید ی معیشت نہ تو کسی حتمیت کی طرف دار ہے نہ لازمیت کی۔ اس میں مکالماتی لچک ہے جو موضوعاتی تنوع میں کشش کا سبب بنتی ہے۔
اپنے پہلے مضمون’’ تنقید ایک خود مکتفی علم ہے‘‘ میں درویش تنقید کی آزادی کا نقیب محسوس ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آزادی کس سے حاصل کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں پہلے مضمون میں ہی مل جاتا ہے:
’’تخلیقی وفور، جوش، جذبہ، خیال آرائی، تخلیقی کرب، جمال دوستی، کِشف، وجدان کا لمحہ اور آدرش جیسی اصطلاحات خود اردو تنقید میں اس قدر بار پا چکی ہیں کہ جیسے ایک تخلیق کار کے لیے یہ اصطلاحات نہیں ہیں بل کہ کوئی آسمانی بند و بست ہے جس میں دخل دینا گویا تخلیق کو فنا کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک تخلیق کار خدا یا دیوتا تو ہر گز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی فکری تنگ دامنی یا تعصب اور فنی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا اپنا خدائی یا دیوتائی حق سمجھتا ہے۔ یوں دونوں حوالوں سے گرفت کرنے والا ناقد مغضوب اور معتوب قرار پاتا ہے۔‘‘
مزید و متعلقہ: یہ مسائلِ فسانہ از، ابرار مجیب
اردو کا نیا فکشن از، معراج رعنا
ثقافتی تھیوری اور ما بعد جدیدیت: عصری فکری مسائل از، فرخ ندیم
یہ سوال کتنا دل چسپ اور اہم ہے کہ تخلیق کار کی حساسیت ایک اسطورہ کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کار ایک ایسے استھان پر براجمان ہے کہ جو ما وارئے تنقید و احتساب ہے؛ یعنی جین آسٹن کے نسائی کردار ایما کی طرح تخلیق کار always first and always right کے اسطورہ کا بری طرح شکار ہوتا ہے اور کسی طرف سے کسی بھی قسم کا سوال تخلیقی تقدس پر شب خون مارنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ چُوں کہ ادیب حساس ہے اس لیے اس کا لکھا ہر لفظ ما بعد طبیعیاتی چمتکار یا کوئی ہلالِ احمر ہے جس پر کوئی تنقیدی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ درویش جانتا ہے کہ ما بعد جدیدیت کے عہد میں ہر چھپ جانے والی تحریر کی ملکیت عوامی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب اس کی تفہیم و تعبیر میں لکھاری کی طرف سے رکاوٹ ڈالے جانے کا عمل علمی روایت کی نفی سمجھا جاتا ہے۔ تخیل اور تجلی کے گٹَھ جوڑ سے پیدا ہونے والا محلُول ثقافتی نرگسیت کا ترجمان ہی کہلائے گا، عوامی نہیں ہو سکتا، یار لوگ یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔
درویش کا مضمون ’’تنقید ایک خود مکتفی عمل ہے‘ ایک تنقیدی مینی فیسٹو ہے لیکن اتنا ہمہ جہت ہے کہ ایک ایک جملے پر بحث کی گنجائش موجود ہے: مثلاً ایک پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ درویش کا تصورِ نقاد کیا ہے۔ کیا ہر نقاد کے ہاں تنقیدی سنجیدگی موجود ہے؟ یہ معاملہ تنقیدی موضوعیت کا ہے جس کی ساخت میں بہت سے عوامل کارِ فرما ہوتے ہیں۔ اس مضمون کے عنوان’’ تنقید ایک خود مکتفی عمل ہے‘‘ میں بھی یہ گنجائش موجود ہے۔ یعنی، شرحیاتی ڈسکورس کی رو سے، یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ درویش کے خود مکتفی عمل سے کیا مراد ہے۔ اس مضمون میں درویش قاری کے سامنے دفعِ بَلیات پیش کرتا ہے جس کے باعث قاری کا ٹھوس نظریاتی بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ دنیا کو ایک کونے سے نہیں بَل کہ بڑے منظر نامے سے دیکھنے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ عام طور پر قاری کو مہا بیانیوں کی ایک طویل فہرست تھما دی جاتی ہے جس کی رو سے ہر فن پارے کو پرکھا جانا لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ یوں درویش کی تنقید مکالماتی، جدلیاتی ہونے کے ساتھ مادی حقائق کی اہمیت کا شعور دیتی ہے۔ اپنے مضمون ’’تنقید سے ڈرنا‘‘ میں درویش نے قاری کی فکری تربیت کی کوشش میں فرانسیسی مفکر ژاں پال سارتر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے:
’’ژاں پال سارتر نے جب فرانز فینن کی کتاب ’’افتاد گان خاک‘‘ کا پیش لفظ لکھا تو اسے اس بات کی کوئی پروا نہ تھی کہ یورپ اور امریکہ کے سفید چمڑی والے لوگ نو آبادیاتی نظام کے ظلم و استبداد کے بارے میں اس کی رائے کا احترام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اسے تو بس ایک سچی تحریر درکار تھی، ایک ایسی سچی تحریر جسے خود اس بات کی پروا نہ تھی کہ نسلی عصبیت کے خلاف اس کا ردِ عمل اقوامِ عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے یا نہیں جھنجھوڑتا۔‘‘
اس قسم کی تخلیقی بے باکی درویش کا آئیڈیل فکری جغرافیہ ہے جو عقل و استدلال کے ساتھ ہمارے قارئین کی تنقیدی تربیت کا سبب بن سکتا ہے۔ شکست خوردگی کے لا متناہی سلسلوں نے یاسیت کی ایسے پرورش کی ہے جیسے کچھ لوگ کھریڑوں کو چھیڑ کر لذت کشید کرتے ہوں۔ درویش کے مباحث کی رو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کار کا نقاد سے بیک وقت محبت اور نفرت کا رشتہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر عہد حاضر میں تخلیق کار کو ناقد سے کسی خاص تعین کاری کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ ادبی تھیوری کے بعد جس قسم کی تنقید سامنے آ رہی ہے اس میں فن پارے کو پرکھنے کی بیسیوں جہات اور زاویے ہیں۔ یہ تنقیدی اختصاص کا دور ہے۔ sweeping بیانیوں کا دور تیزی سے گزر رہا ہے ۔ اب ایک ہی بندہ، بغیر کسی تربیت کے، ایک ہی وقت میں جب شاعری کی تمام اصناف، ہر قسم کے ناول افسانے، خاکوں اور یہاں تک کہ داستانوی ادب پر بھی خامہ فرسائی کرتا ہے تو جیک آف آل ٹریڈز والی صورت حال نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر مضمون ’’آزادیِ اظہار، پلیخانوف اور ہم‘‘میں درویش نے لفظ ’’رائے‘‘ کی سماجی اور ثقافتی اہمیت، سیاست اور آمریت پر (میرے خیال میں نامکمل) بحث کی ہے۔ درویش نے روسی مارکسی مفکر پلیخانوف کو عقل و استدلال کی علامت ٹھہرایا ہے جب کہ سماج میں مروج خواہ مخواہ کی ’پلیخانوفیت‘ کی ردِ تشکیل کی ہے۔ رائے دینے اور قائم کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ طاقت ور طبقے ہر سماج میں رائے قائم کرتے ہیں جب کہ عام افراد میں سے بھی کچھ منتخب لوگ ہی رائے دینے کے اہل سمجھے جاتے ہیں بھلے کسی عام فرد کی رائے کتنی ہی متوازن کیوں نہ ہو اسے سندِ قبولیت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ طاقت ایک آسیبی بھلیکھا ہے جس کے سامنے بڑی سے بڑی اور اہم معقول بات بھی ’’رائے زنی‘‘ ٹھہرتی ہے۔
مشرق اور خاص طور پر بر صغیر کے دانش وروں میں فکری ارتقا کو سمجھنے کی کوششیں بہت کار گر ثابت ہوئی ہیں۔ خاص طور پر یونانی ادب، تھیٹر اور فلسفہ کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ ہماری تنقید اس کے بغیر ردِ استدلال نظر آتی ہے۔ کلیسائی ساختوں کے رد عمل میں نشاۃِ ثانیہ کا ظہور ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے رات کی تاریکی پھلانگتے سورج کی کرنیں انسان دوستی کا سواگت کرنے نکلی ہوں۔ انسانی تحرک کا عظیم پڑاؤ اسی عہد کو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مغربی جدیدیت کی ابتدا بھی اسی دور سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر درویش کا اگلا اہم مضمون بھی جدید حسیت پر ہے جس میں ڈاکٹر درویش عام فکری چلن کو مادی محرکات کے ذریعے سے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ بہ ہر حال کچھ مباحث لمبے سانس کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ایک تجسس تھا کہ درویش ترقی پسندوں، لبرلسٹوں اور دائیں بازو کے مباحث، سوالات اور اعتراضات کے حوالوں سے اس بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے لیکن درویش کے مد نظر ایک اور اہم سوال تھا، وہ انسان کے ارتقا میں اس کی کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور ان کی تعبیر کرنے میں خود انحصاری کا معنی خیز فروغ ہے۔ نشاۃِ ثانیہ سے شروع ہونے والے جدیدیت کے اس ان تھک سفر نے اس نئے انسان کو حقِ تشکیک ’’عطا‘‘ کیا جو اسے سماجی معاملات میں خود کفیل متشکل ہونے کا باعث بنا۔ درویش اس انسان کی فکری ولاسٹی کو یوں سمیٹتا ہے:
’’نئی زندگی کی نئی عمارات، تصویریں، مجسمے، ظروف، ملبوسات وغیرہ میں انسان کو اپنے ہنر کی عظمت دکھائی دینے لگی۔ اس نے پہلی مرتبہ جانا کہ وہ لائقِ تعریف ہستی ہے۔ کائنات کی عظیم وسعتوں کے مقابلے میں اسے پہلی مرتبہ یقین آیا کہ خود اس کے اپنے ہاتھوں سے تخلیق پانے والے تمدن کا جنم ایک ایسا شاہکار ہے کہ فطرت کی بو قلمونیوں میں اس سے مقابلہ تو کیا مشابہت تک موجود نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں سے تخلیق پانے والا ہر فن پارہ اپنی مثال آپ تھا۔ اپنے تمدن کے مادی مظاہر کے حسن کا خالق وہ خود تھا۔ اپنی فنی لیاقت اور وسائل اور مادی ذرائع کے تخلیقی اظہار کے لیے اس کا اپنا دریافت کدہ علم بھی تھا کہ جس کی معقولیت کا جواز بھی اس کے پاس موجود تھا۔ کائنات کی ابتداؤں اور انتہاؤں کے بارے میں اس کی اوہام سے معمور دنیا کے مقابلے میں اس کی اپنی تشکیل پذیر اور ارتقا پذیر دنیا زیادہ منطقی، حقیقی اور سمجھ آنے والی تھی۔‘‘
اس انتہائی دل چسپ اورپر مغز پیراگراف میں درویش کی فکری بے باکی قابلِ تحسین ہے۔ ما بعد نشاۃ ثانیہ انسانی ذہن کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے درویش قرون وسطی کی عالم گیر ثقافت کے اتصالی رشتوں کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ اس علمی روایت میں جہاں مسلمانوں کے فکری کنٹریبیوشن کی اہمیت اور کردارکا ذکر ہے :
’’یہ وہ انسانی مادی علوم و فنون تھے کہ جن سے متعلق ابتدائی کام قسطنطنیہ پر ترکوں کے حملے سے پیش تر مسلمان دانش ور سائنس دان اور فلسفی مذہبی احیاء کی تحریکوں سے پہلے کے زمانے میں کر چکے تھے۔ ان علوم و فنون کو سترھویں صدی عیسوی تک اہل یورپ نے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ یہ علوم و فنون اٹھارویں صدی عیسوی تک ارتقا پذیر ہوتے ہوتے بڑے پیمانے پر ہونے والی صنعت کاری میں اپنا حقیقی اور موثر ترین کردار ادا کرنے کے اہل بن گئے۔‘‘
درویش کی اس بحث سے، جدید حسیت کے پس منظر میں، یورپی تہذیب کی روشن خیالی اور ترقی پسندی اور اس کے اسباب جاننے کا مو قع ملتا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ نشاۃ ثانیہ کے بعد یورپی اقوام کو، ان کی روشن خیالی کے باعث، کلی طور پردائرہ عیسائیت یا یہودیت سے خارج سمجھا جائے یا نہیں۔ نشاۃ ثانیہ کے عہد کے ادیب (خاص طور پر کرسٹوفر مارلو ) نظریاتی دو گونیت کا شکار نظر آتے ہیں۔ کلی طور پر یورپی تہذیب ایک ہچکچاتی سیکولر ازم کا سفر ہے۔ خاص طور پر یورپی دانش ور مذہب بیزار نظر آتے ہیں۔ سرکاری سطح پر مذہب کسی نہ کسی صورت میں ان کی پالیسیوں اور عمل داریوں میں موجود رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نو آباد کار (استعمار کی شکل میں) جہاں بھی گیا کراس اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نشاۃ ثانیہ کے بعد بھی خدا اور انجیل کی آڑمیں، انفرادی اورگروہی سطحوں پر نئے سرمایہ دارانہ نظام کو پاپولر کلامیوں، بیانیوں کی ضرورت تھی۔ اپنے اعمال کی جسٹی فیکیشن کی خاطر طاقت ور جماعت کو خدا اور اس کے کلام کا سہارا لینا پڑتا ہے، جگہ یورپ ہو یا کوئی اور، فرق نہیں پڑتا۔ طنز و مزاح سے رنگی ایک ما بعد نو آبادیاتی کہانی ہے کہ جب انگریز ہمارے علاقے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں بائبل تھی اور ہمارے پاس زمین۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ خدا کا کلام انجیل مقدس ہے۔ پھر اس نے کہا عقیدت سے اپنی آنکھیں بند کرو اور ہاتھ پھیلاؤ۔ ہم نے عقیدت سے ہاتھ پھیلائے۔ جب ہم نے آنکھیں کھولیں تو ہمارے ہاتھوں میں انجیل مقدس تھی، اور، اس کے ہاتھ لگ چکی تھی، ہماری زمین۔
اردو ناول کے ابتدائی مراحل اور اس کے سیاق و تناظر کے سلسلے میں درویش کا مضمون’’1857ء: تناظرات، مسائل اور اردو ناول‘‘ خاص طور پر ناول پر تحقیق کی بابت بہت اہم ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے وہ اسباب جو ہم سب نے مطالعہ پاکستان کے ایک ’’سنہری باب‘‘ میں پڑھ رکھے ہیں، وہ درویش کی رد تشکیل کا نشانہ بنتے ہیں۔ یہ مضمون ایک عمدہ ریسرچ پیپر ہے جس میں برطانوی راج سے پہلے کی اس ثقافتی، سیاسی، زرعی اور تجارتی صورت حال کا جائزہ لیا گیا ہے جو بعد ازاں ایک بڑے، علم اور طاقت کے گٹھ جوڑ سے تعمیر شدہ، سائنسی طرز کے انگریزی نظام کے مقابلے میں شکست و ریخت کا شکار بنی۔ یہاں بھی درویش رجعت پسند ذہنیت کی پسپائی کو اس کے قدامت پسند ذرائع پیدا وار سے مشروط دیکھتا ہے۔ تاریخ کا ریکارڈ اور مزاج درست رکھنے کے لیے اس قسم کے مضامین بہت ضروری ہیں اوراس میدان میں درویش کا مطالعہ جینیاتی حد تک گہرا اور فکر انگیز ہے۔
اسی طرح ایک اور مضمون’’ فلسفۂ تہذیب‘‘ نہ صرف درویش کا تصورِ تہذیب پیش کرتا ہے بل کہ اس تہذہب کا تمدن سے فرق اور اس کی ساختیاتی جہتوں میں تشکیل پانے والے فرد کا تشخص بھی زیرِ بحث لاتا ہے۔ انسان، مرد ہو یا عورت، دونوں کی اپنی اپنی موضوعیت ہوتی ہے لیکن بشریاتی حوالوں سے دونوں کی تشکیل میں مادی اور ثقافتی عناصر اور عوامل کے کردار کو عام طور پر نظر انداز کر کے اس کی تفہیم و تعبیر کی جاتی ہے جو کہ سرا سر غیر سائنسی اندازِ فکر ہے جو ہمارے متون میں زبر دستی گھس چکی ہے۔ تہذیب اور ارتقا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں درویش کا تصور تہذیب پروگریسو حد تک منطقی ہے۔ یعنی تہذیب ترقی معکوس سے رگڑ کھاتی ہے۔ اس کی ساخت میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں حالتیں شامل ہیں اور کسی ایک حالت کے غائب کرنے سے ارتقا کا تہذیبی سفر یا تہذیب کا ارتقائی سفر نامکمل حد تک غیر جدلیاتی اور ردِ تہذیب سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں درویش کا کہنا ہے:
’’رد تہذیب کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی تہذیب و تمدن کا دائرہ تکمیل ریاستی ترجیحات، سیاسی و معاشی قوانین اور تنظیمی ڈھانچہ، اندرونی اور بیرونی سطح پر جنم لینے والے سیاسی، سماجی اور معاشی تضادات کی نئی صورت پذیری کو پرانے تہذیبی و تمدنی نظام کے تابع رکھنے پر مُصر ہو جاتا ہے۔ قانون کی بالا دستی کا اصول مقدس دیوتا بن جاتا ہے اور آسودہ زندگی کے نئے امکانات کو اُس کی بھینٹ چڑھانا عبادت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ ریاست تہذیبی اور تمدنی زندگی میں ہر تبدیلی کو معاشرے کے لیے نا سُور قرار دیتی ہے۔‘‘
مضمون ’’ادب، لبرل ازم اور تمدن جدید‘‘ میں بھی درویش نے ثقافتی ساختوں کا انتہائی اہم سائنسی مطالعہ پیش کیا ہے جس میں لبرل قدروں کو شناختی مظاہر سے تضاد کی صورت پیش کیا ہے۔ کتنا غور طلب اور حل طلب قضیہ ہے کہ ’’شناخت کا ہر مظہر دیگر تمام مظاہر پر غلبہ پانے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔‘‘ اس مضمون سے ایک اہم سوال ابھرتا ہے کہ کیا شناخت کسی بائنری سے مشروط ہے؟ ظاہر ہے یہ نا ممکن ہے، تو اس صورت میں نظریاتی جبر کا وجود بذاتِ خود سوالیہ ہے جس سے عصری تنقیدی خاص طور پر ما بعد نو آبادیاتی متون بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ اردو دنیا میں ان سوالات کا فقدان ہے اس لیے کہ یہاں ہر قسم کی شناخت بھلے وہ طبقاتی ہو، کو ما بعد الطبعیاتی متون سے جسٹی فائی کیا جاتا ہے۔ درویش شناخت کو تعصب سے پاک نہیں سمجھتا۔ اس نکتے کو سمجھنے کے لیے شناخت ساز کارخانوں اور شناخت سازی کے مراحل کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ کسی بھی ثقافت میں کسی فرد (مرد و زن) کا فعل کی صورت میں شناختائے جانا معنی خیز ہے۔ عورت اور مرد کہاں تک نیچرل اور کہاں تک کلچرل ہیں، یہ قضیہ پسِ ساختیاتی مفکرین کے تنقیدی متون کا اہم سرو کار ہے۔ لیکن اردو میں ان مباحث کا انعقاد اور اس روایت میں درویش کے مطالعہ کا کردار اردو دنیا کی پسِ ساختیاتی روایت میں سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پسِ ساختیاتی روایت میں شناخت اور آئیڈیالوجی ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں۔ اب چُوں کہ اس بحث میں آئیڈیالوجی کو جبر سے منسلک کر کے دیکھا جاتا ہے اس لیے اس کے لفظی یا لغوی معنی بے شک بلا تعصب ہوں، ثقافتی معنی گروہی طاقت اور اس کے استحصالی اور استعماری حربوں پر دال کرتے ہیں۔ یہ مضمون بھی پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
اس کتاب میں ایک نہیں کئی ایک مضامین ہیں جو قاری کے لیے سوچ کے نئے در وا کرتے ہیں۔ ایک اچھی تحریر بے مقصد نہیں ہوتی، اگر کوئی مضمون انسان کی موضوعیت پر بے اثر رہتا ہے تو وہ مضمون یا فن پارہ مروج کلامیوں کا ترجمان ہے، کسی نئی سوچ کا نہیں۔ مجموعی طور پر درویش انسانوں کو نظریاتی آلائشوں سے پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اپنی تحریروں، مباحث اور مکالموں میں بھی درویش ردِ کثافت نقاد نظر آتا ہے۔ وہ خود بھی بلا کا سہولت پسند ترقی پسند ہے۔ اگر کہیں بحث طویل اور تلخ ہو جائے تو دو چار گالیاں اور لمبا سا قہقہہ، یہ درویشی اختصاص ہر محفل میں ایک مثبت حرکی توانائی کا کام کرتا ہے۔ اسے طبیعتوں کے بھاری پن سے نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ، ڈاروینی ہیومینسٹوں کی طرح، بلا وجہ سسی فس کے بوجھ تلے پھنسنے والوں پر نہ صرف ہنستا ہے بل کہ قہقہے لگاتا ہے۔ وہ اپنی قوم کے کیسا بیانکا پن سے بھی سخت بیزار ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ لوگ اس کی زندگی میں ہی (اسمِ) ضمیری ساختوں سے آزاد ہوں تا کہ ثقافتی ماحول واضح حد تک شفاف ہو اور اصل انسانی اقدار کو رجعت پسند قید سے رہائی ملے۔ دوسر ی صورت میں اپنی نا گزیر تباہی اور بربادی کا نظارہ کرتے لا یعنی کہرام نہ مچائیں، بل کہ، اس نقصان کو رضا کارانہ طور پر اور خندہ پیشانی سے قبول و منظور فرمائیں، کیوں کہ سماج میں مقبول بیانیوں کے مطابق یہی افقی اور آفاقی امر ہے۔
درویش کی ہنسی اتنی لا جواب ہے جتنی بیساکھیوں کے سہارے چلنے والی روایتی فکر اور ترقیِ معکوس کے خلاف اس کی بیزاری۔ وہ روشن خیال جمہوری قہقہے لگاتا ہے اور پوری دیانت داری سے لگاتا ہے، بھلے مارکسی اور دائیں بازو کے دانش ور اس کے قہقہوں کے آلاپ میں شامل ہو ں یا نہ ہوں۔ وجودی دائروں میں الجھے ہوئے آدرش ہوں یا ہلکی آنچ پر پکی ہوئی کچی پکی غزلیں، سیاست دانوں کی لسانی تراکیب ہوں یا ریاستی بیانیوں سے اٹے افسانے، سوشل میڈیا پر پیش کیے جانے والے چٹخارے دار تبصرے ہوں یا ادبی سیاست میں اپنا اپنا غیر غیر کا کھیل، وہ سب پر کھل کر اور پورے وفور سے قہقہے لگاتا ہے۔ ادبی متون کے اندر نظریاتی پیوند کاری کو وہ خوب پہچانتا ہے خاص طور پر اس صورت میں جب روایتی خیر و شر کی (نام نہاد) جنگ پوری نظریاتی صداقت سے لڑی جا رہی ہو، درویش اتنی ہی صداقت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ لیکن اپنے قہقہوں کے لیے کچھ خاص تگ و دو نہیں کرتا بل کہ اکثر اوقات یہ مواد اس کے پاس خود پہنچ جاتا ہے۔ قصہ مختصر وہ جمودی ساختوں سے چمٹی چمٹائی عبارتوں سے خوب لطف لیتا ہے۔
درویش کے حلقہ احباب میں اتنا ہی تنوع ہے جتنا امریکی یا یورپی ما بعد جدیدیت میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک ساختیاتی صداقت کی حیثیت سے رہتا ہے۔ یہاں اس کے دوستوں میں شیعہ، سنی، نیم شیعہ، نیم سنی، نیم مارکسی، کٹر مارکسی، اہلِ حدیث، دیوبندی، لبرل سیکولر تقریبا تمام مکاتبِ فکر کے دانش ور شامل ہوتے ہیں اور اکثر ہوتے ہیں۔ آج کے عہد کی تقسیماتی سیاست میں ایسا شخص بلا شبہ ڈھٹائی کی حد تک روشن خیال ہے۔ ممکن ہے اس کی کوئی مِتھ شکن بات کہیں کہیں نا گوار گزرتی ہو لیکن احباب کو خوشی ہے کہ وہ مِتھ فروش نہیں۔ ایسا شخص کم ہی ملتا ہے جو خود لکھتاہو:
’’میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ میرے مضامین آفاقی تحریریں نہیں ہیں بل کہ ان کی بنیاد ہی افکار کی آفاقیت یا ان کی قبولیتِ عامہ کو چیلنج کرنا ہے۔‘‘